درّہ آدم خیل کی تتلیاں
ہمارے پیارے ملک میں ایسی بہت سی جگہیں ہیں جہاں زندگی کی قیمت ایک سستی گولی سے زیادہ نہیں ہے۔ سستے اسلحے کے روزمرہ کے سامان میں شامل ہو جانے کے نتیجے میں عام شہریوں کی سانسیں قرض بن گئی ہیں۔ لیکن ایسی بھی جگہیں ہیں جہاں سستی موت نہیں بکتی۔ ایسی جگہوں کے متعلق سچ سننے کو بہت کم ملتا ہے۔ جو بھی ایسے علاقوں کی بات کرتا ہے، اپنی کہانی میں مبالغہ آرائی اور ایکشن فلموں کا مصالحا ملانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا۔
مملکت خداداد کی راجدھانی سے بمشکل پانچ گھنٹوں کے فاصلے پر، اور تبدیلی کے پھولوں سے مہکتے ہوئے باغ جیسے صوبے کے ہیڈکوارٹر سے دو ایک گھنٹے کی ڈرائیو پر واقع یہ چھوٹا، دیہات کی چادر تلے ڈھکا شہر انہی غلط فہمیوں کا شکار ایک مقام ہے۔
شوقین اور حادثاتی غنڈے ملک میں جہاں جہاں سستی موت کا کاروبار کرتے ہیں، اکثر اسی چھوٹے شہر میں تیار کئے جانے والے اسلحے کا استعمال کرتے ہیں، اسی سبب زیادہ تر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ جگہ قاتلوں کا ڈیرہ ہے، ظالموں کا گھر ہے یا پھر کوئی موت کی وادی۔
درّہ آدم خیل۔ اپنے پسندیدہ انٹرنیٹ سرچ انجن میں یہ نام لکھ کر دیکھیں کیا کیا نتائج رونما ہوتے ہیں۔ طالبان کی خبریں، بم دھماکوں کی خبریں، افواہیں کہ یہ علاقہ پاکستانی ایجنسیوں کا خفیہ کارخانہ ہے۔ گولیاں، بارود، بندوقیں، اسلحہ اور ایسے الفاظ جو ایک لمحے کو تو دل میں دہشت بٹھا دیتے ہیں۔
گاڑی سے اترے ہی تھے کہ سماعتوں کو سُن کر دینے والی ایک آواز سنائی دی۔ قریب ہی کہیں کسی بھاری بھرکم رائفل کا منہ کھلا تھا۔ جتنی دیر میں اس پٹاخے کے بارے ہم میں سے کوئی کچھ کہتا، ایک اور گولی کی آواز سنائی دی۔ اسی طرح یکے بعد دیگرے گولیاں چلنے کی آواز آتی رہی، ایک نہ رکنے والے سلسلے کی طرح۔
ہماری جان کو تو ہر گولی کی آواز عذاب تھی، مگر درے کے لوگوں کے لئے یہی آواز اس طرح عام تھی جیسے پتوں کی سرسراہٹ۔ لوگ تو لوگ، وہ پہاڑیاں بھی بار بار گونجتے ان دھماکوں پر برا نہیں منا رہی تھیں۔
"سن رہے ہو بھائی،" میرے دوست ارسلان نے مجھ سے کہا، "یہ درّہ ہے میرے دوست!"
میں اس وقت صرف یہی سوچتا رہا کہ کاش میں گھر پر ہی رہتا تو نیند کی وادیوں میں کھویا ہوتا۔
ہم پانچ دوست کسی کے مدعو مہمان تھے۔ خاص طور پر اپنے میزبان کے حجرے پر کچھ وقت گذارنے گئے تھے۔ ہمارے میزبان منیب آفریدی، جو کہ ایک اسلحے کے کارخانے کے مالک ہیں، ہمیں خوش آمدید کہنے کو ہماری آمد سے قبل ہی وہاں موجود تھے۔ "مڑا، تم لوگ بہت جلدی آگیا" ان کے ہونٹ ایماندارانہ مسکراہٹ اٹھائے پھیل گئے۔ اور یوں ہمارا درہ آدم خیل کی اسلحہ بازار کا دورہ شروع ہوا۔
اپنی گاڑی سے ابھی ہم کچھ ہی قدم چلے تھے کہ ہم دوستوں نے دو نوجوانوں کو دیکھ کر ایک دوسرے کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ یہ دو نوجوان مخصوص انداز کی پگڑی سر پر باندھے ہوئے تھے، کالے رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی، دونوں ہی کی شلوار ٹخنوں سے اوپر تھی، دونوں نوجوانوں نے ایک ہاتھ میں کلاشنکوف پکڑ رکھی تھی، اور دوسرے ہاتھ میں موبائل فون۔ معلوم ہوتا تھا کہ اسی موبائیل فون کے متعلق گفتگو میں مشغول ہیں۔
اگر ان کے ہاتھوں میں وہ رائیفلیں نہ ہوتیں تو ہمیں ان میں اتنی دلچسپی نہ ہوتی۔ ہم میں سے ایک دوست نے ہمارے میزبان سے معلوم کیا، "کیا یہ طالبان ہیں؟" جواب ملا، "وہ طالبان نہیں، اچھے طالبان۔"
میں ان کے اس جواب پر خود کو طنزیہ ہنسی ہنسنے سے روک نہ سکا۔ اب جب سوچتا ہوں تو یاد آتا ہے ان کا چہرہ شاہد تھا کہ وہ میری نیت بھانپ چکے تھے۔ تبھی انہوں نے مسکراہٹ ہونٹون سے غائب ہونے نہیں دی، اور کہا؛
"ہاں، اچھے طالبان، جو برے طالبان سے لڑتے ہیں۔"
اپنے جواب کے لفظ لفظ پر وہ استاد کی نگاہیں لئے تھم تھم کر میری جانب دیکھ رہے تھے۔
سدھرے ہوئے شہری شہزادے کی نظر میں درہ آدم خیل کا اسلحہ بازار دل دہلا دینے والے مناظر سے بھرپور ہو شاید۔ سیمنٹ کی ٹرالیوں پر وافر مقدار میں گولیاں بھرے لئے جاتے لوگ ایسے اپنے کام میں مگن تھے جیسے میلے میں قلفی کی ریڑھی والا۔ یہ گولیاں درے کے ان باشندوں کے لئے معیشت کی تعمیر میں کام آنے والے سیمنٹ ہی کی طرح ہیں۔
نوجوان، ضعیف اور بچے ہاتھوں میں اسلحہ پکڑے اپنی اپنی منزل کی جانب یوں رواں دواں نظر آرہے تھے جیسے کسی بڑے شہر کے مصروف بازار میں لوگ آس پاس کسی چیز پہ دھیان دیئے بنا اپنے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں۔ فرق اتنا تھا کہ کسی بڑے شہر کی بہ نسبت یہاں مسکراہٹیں گولیوں اور اسلحے کی طرح ہی زیادہ عام تھیں۔
حالانکہ ہماری نظر میں ان کے پاس خوش ہونے کے لئے کچھ بھی تو نہیں تھا۔ لیکن جب آپکو پتہ چلے کہ ایک عام مزدور بھی یہاں 30 سے 35 ہزار ماہانہ کما لیتا ہے تو پھر اس مسکراہٹ کا معاشی سبب تو کم از کم سمجھ آ ہی جاتا ہے۔
حجرے پر جا کر آرام کرنے سے پہلے منیب صاحب ہم دوستوں کو اپنے ایک دوست کی دکان پر لے گئے۔ پرچون کی دکان میں بیٹھتے تو شاید اتنا اچھا نہ لگتا، مگر یہ ہماری نظر میں کوئی عام دکان نہیں تھی۔
دکان اتنی چھوٹی تھی کہ ہم 9 لوگ اس میں بیٹھ نہیں پارہے تھے۔ ہمارے میزبان منیب صاحب اور ان کے احباب تقریباً دکان سے باہر جاکر بیٹھ گئے تاکہ ہم آرام سے بیٹھ سکیں۔
ہماری سروں کے اوپر جنگ کے باغات کے پھل لٹک رہے تھے، افغانستان کی اس جنگ کی نشانیاں جس نے آج تک اس خطے کے حالات اپنے اثر سے آزاد نہیں ہونے دئے.
"کیا میں ایک رائفل دیکھ سکتا ہوں؟" میں نے منیب صاحب سے پوچھا۔ پوچھنے کے فوراً بعد احساس ہوا کہ میں نے بچوں والی بات کر دی ہے۔ میری شرمندگی کو چار چاند لگاتے ہوئے انہوں نے مجھے اس طرح جواب دیا جیسے خوش مزاج والد میلہ گھمانے لائے اپنے بچوں کو کھلونے کی فرمائش پر اقراری جواب دیتا ہے:
"ایک نہیں، سب دیکھ سکتے ہیں آپ۔"
ایک ایک کر کے ہم سب نے خالی رائفلیں اٹھائیں، دیکھیں، شوقینوں کی زبان میں، چیمبر کیں، ٹرگر دبا کر ٹک ٹک کی، اور ان لکڑی اور لوہے کے انوکھے میلاپ کے نمونوں کو سہلاتے رہے۔
میں اسی کھیل میں مگن تھا کہ برابر میں بیٹھے میرے دوست نے پکارا، ”لغاری!“ مڑ کر دیکھا تو میری نظر موت کے کنویں جیسی عبرتناک بندوق کی نلی پر پڑی۔ اس نے ٹریگر دبایا اور ایک لمحے کے لئے میرے جسم سے سانسیں رخصت ہو گئیں۔
یہ یاد کرنے میں مجھے ایک دو سیکنڈ لگے کہ رائفل خالی تھی۔ شاید یہ مسلسل سنائی دیتی گولیوں کی آواز تھی جس سے میں ڈر گیا تھا۔ قصائی کی دکان پر جیسے گوشت کی بو آپکے حواس کو ایک پل بھی آرام نہیں لینے دیتی، درے میں فائرنگ کا کچھ یہی قصہ ہے۔
شکر ہے کہ وہ لوگ بم گولے نہیں آزماتے۔ میں نے اسی خیال کے ساتھ قہوہ پیالے میں بھرا اور سرکیاں بھرنے لگا۔ زندگی میں آج تک اتنا مزیدار قہوہ میں نے نہیں پیا تھا۔
کلاشنوں کے بعد دیگر رائفلوں کی باری آئی، 12-بور، پھر کچھ اور ہی نسل و رنگ کی رائفلیں۔ میں نے پہلی بار ایل پچینو اور مارلن برانڈو کی مشہور زمانہ فلم گاڈ فادر جیسی فلموں میں استعمال کی جانے والی ٹامی گن جیسی سب مشین گنیں بھی دیکھیں۔ مقامی سطح پر تیار کی جانے والی پستولیں بھی نظر آئیں جن میں زیادہ تر عالمی سطح پر مقبول کمپنیوں کی پستولوں کی نقل تھیں۔
ان سب کے علاوہ گولیوں کی قومیں بھی دیکھیں، کوئی روسی، کوئی جرمن اور کوئی چینی۔ میں سوچ رہا تھا کہ کسی کو موت کی نیند سلاتے وقت بھی یہ گولیاں کیا اپنی قومیت برقرار رکھتی ہونگی؟ پاکستانی گولیاں بھی تھیں، شاید یہ گولیاں اپنی اپنی بندوقوں کی نلیوں سے نکلتے وقت اپنے فرقے کا نعرہ لگاتی ہوں!
میں کوئی ماہر معاشیات تو نہیں، نا ہی کاروبار میں کوئی خاص دلچسپی رکھتا ہوں، لیکن اس بازار کا ایک ہی دورہ مجھ پر یہ آشکار کر گیا کہ یہ ملک کے سب سے کامیاب بازاروں میں سے ایک ہے۔
تکنیکی لحاظ سے، جو معیار چینی اسلحے کا ہوتا ہے، اسے یہی پاکستانی صنعت باآسانی مات دے سکتی ہے۔ جب ایران میں بنی ہوئی رائیفلیں پاکستان میں بک سکتی ہیں تو پاکستان کا اسلحہ باہر کیوں نہیں بک سکتا؟
اس صنعت کو قانونی لبادہ پہنانے میں پاکستانی انتظامیہ کو زیادہ مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ایک جھوٹی انا کی خاطر، بالکل جیسے فوجی جرنیلوں سے لے کر پولیس اور سیاست کے ساتھ ساتھ ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے پاک آستانی، شراب پینا تو خوب پسند کرتے ہیں، مگر اس امر کی قبولیت کو تسلیم نہیں کر سکتے، اسی طرح کچھ طاقتور اور کئی کمزور مل کر درے جیسی صنعتی حقیقتوں کو مشکوک ہی رکھنا چاہتے ہیں۔
منیب صاحب کے دوست نےہمیں بتایا، "ام سے کبی کبی ایک کسٹمر پانچ چے ازار (رائفلیں) بی لے جاتے۔"
اپنے دوست کو غیر زبان پر مزید زور آزمائی سے نجات دلاتے ہوئے منیب صاحب نے بات آگے بڑھائی؛
"زیادہ تر شکاری ہوتے ہیں۔ ان کے لئے یہ رائیفلیں ڈسپوزیبل اسلحہ ہیں جسے وہ استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں"۔
وہیں موجود منیب کے ایک اور دوست نے بتایا کہ؛
"یہ شکاری اکثر افغان ہوتے ہیں۔ شکار کے دن گذر جانے کے بعد سارا بیکار اسلحہ زمین میں گاڑ دیا جاتا ہے۔ پھر امریکی فوجیوں سے رابطہ کیا جاتا ہے اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ طالبان کا سامان دریافت ہوا ہے۔ امریکی آتے ہیں، خبر دینے والے کو انعام دیتے ہیں، اور بیکار اسلحہ توڑنے پر فضول توانائی لگا کر لوٹ جاتے ہیں"۔
کچھ افغان تو خاص طور پر اسی مقصد کے لئے مقامی اسلحہ فیکٹریوں سے بیکار رایئفلیں بنواتے ہیں کہ امریکیوں کو بیوقوف بنا کر اچھے دام وصول کرینگے۔ خیر، اس بات سے امریکیوں کی بیوقوفیوں پر گفتگو شروع ہوئی۔ منیب اور ان کے دوست بتانے لگے کہ کیسے امریکیوں کو ہتھیاروں کے بارے کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ ان کا ماننا ہے کہ ٹیکنالجی نہ ہوتی تو امریکی فوج طالبان کے آگے ٹک نہ سکتی۔ البتہ وہاں موجود تمام حضرات اس بات پر متفق تھے کہ روسی بڑے دلیر فوجی تھے، یہاں تک کہ میں بھی اس بات سے اتفاق کئے بغیر نہ رہ سکا۔
جھولیوں میں رائفلیں، ہاتھوں میں پستول اور باتیں جنگوں اور لڑائی کے پینتروں کی۔ اس سب میں مجھے اچانک یہ یاد آیا کہ اسلام آباد تو گرمی سے تپ رہا ہے۔ حتٰی کہ صبح جب ہم نے سفر کا آغاز کیا تھا، تب بھی حبس کی وجہ سے سانس لینا مشکل تھا۔ ایئر کنڈیشنر کے بغیر اسلام آباد میں گرمیاں گذارنا اپنے آپ کو زندگی سے مزید نفرت کرنے پر مجبور کرنے کے مترادف ہے اور پھر بجلی کی آنکھ مچولی اور پسینے!
لیکن درّے میں موسم کچھ اور ہی تھا۔ دھوپ جاڑے کی میٹھی دھوپ جیسی تھی، بجلی تھی یا نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں جب حجرے کی جانب جانے لگے تو گاڑی میں بیٹھنے کی بجائے میں نے پیدل چلے کا فیصلہ کیا۔ منیب اور ہمارے دو دوست بھی ہمراہ ہو لیے۔
بازار سے باہر نکلتے ہی درے نے اپنے اصل رنگ دکھائے۔ ہری بھری پہاڑیاں جن میں بہار کے موسم کا انتظار سانس لیتا محسوس ہوتا تھا، کھیل کود میں جٹے بچے، اسکولوں کی وردیاں پہنے نوجوان بھی نکڑوں کی پہریداری میں لگے تھے. اپنی اپنی زمین کے ٹکڑے پر مشقت کرتے قدرت کے محبوب لوگ، مال مویشی، دل کو تازگی کے احساس سے نوازتی، سرگوشیاں کرتی ہوائوں میں لہلہاتے پھول۔ میں حیران تھا کہ بارود کی بو اس خوبصورتی سے خوفزدہ ہوکر کہان چھپ گئی!؟
منیب صاحب نے مجھے انگلی کے اشارے سے پہاڑیوں پر اپنی کوئلے کی کانیں دکھائیں۔ "کوئلہ ہمارے لئے ایک نعمت ہے۔" مجھے تب اندازہ ہوا کہ انہوں نے اپنے چہرے کو ایک لمحے کو بھی مسکراہٹ سے آزاد نہیں کیا تھا۔ میں نے ان کی بات کا جواب طنزیہ لہجے میں دیا، "اسلحے جیسی نعمت۔"
منیب کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ پھر انہوں نے ہمیں پہاڑیوں پر ڈیرہ جمائے بیٹھے پاک فوج کے جوان دکھاتے ہوئے کہا، "ان کی وجہ سے اب ہم اسلحہ آزمانے کے لیے ہوائی فائرنگ بھی نہیں کر سکتے۔" میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ کیا یہ یہاں کی سب سے بڑی پریشانی ہے؟
حجرے میں جاکر بیٹھنے سے پہلے ہم سب نے منیب صاحب کی فیکٹری کا دورہ کیا۔ وہاں نوجوان اور ضعیف العمر افراد الگ الگ اپنے یونٹوں میں بیٹھے اسلحے کے مختلف پارٹس بناتے نظر آئے۔ لکڑی اور لوہے کی کٹائی کی آواز درے کے معاشی مستقبل کے تعمیراتی کام کی آواز محسوس ہوتی تھی۔
وہان منیب صاحب کے کارخانے کے منشی سے ملاقات ہوئی۔ منیب صاحب نے ان کا تعارف کرواتے ہوئے بتایا، "یہ 27 برس سے یہیں کام کرتا ہے۔ اسے اب ہم نے ایجنسی کا ویزا دے دیا ہے، اب یہ ہمارا شہری ہے۔"
اس کارخانے میں ہر دن کم از کم 50 سے 60 12-بور رائیفلیں اور بہت سے پستول تیار ہوتے ہیں۔ کارخانے کی حالت کو دیکھ کر یہ کہا جاسکتا ہے کہ مصنوعات کی تعداد حیران کن ہے۔
ابھی ہمارا دورہ جاری ہی تھا کہ ماضی سے دوڑ لگا کر کوئی آواز ہانپتی ہوئی میری سماعت تک پنہچی، ٹن ٹن ٹن ٹن۔۔۔ اسکول کا گھنٹا۔ آگے بڑھے تو سٹی پبلک اسکول کا مرکزی دروازہ نظر آیا۔ یہ اسکول کچھ اس طرح واقع تھا کہ اگر یہ دروازہ داخلے کے لیے استعمال ہوتا ہوگا تو طلباء کو کارخانے کے اندر سے ہی گذرنا پڑتا ہوگا۔
حجرے پر ہمارے لیے اپنے گھروں سے خاص کھانا پکوا کر لایا گیا تھا۔ چرغہ، چپلی کباب اور چاول۔ درے کی خاص روٹی بھی تھی، جو چکھنے کا التماس کرتے ہوئے منیب صاحب کے ایک عزیز نے مجھ سے کہا، "بتائیے یہ روٹی کتنی تازہ ہے؟" میں نے روٹی کھا کر دیکھی تو واقعی بالکل تازہ تھی۔ انہوں نے فخریہ انداز میں بتایا، "یہ سورج اگتے وقت پکی تھی۔" ظہرانے کے بعد پھر قہوے کے دور چلے۔ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں مگر میں نے اس روز اس قہوہ کے درجن پیالے تو پیے ہی ہونگے۔
اس سے پہلے کہ ہم وہاں سے واپسی کا سفر شروع کرتے، مجھے ایک بار پھر پیدل چلنے کا موقعہ ملا۔ پہلے کے مقابلے میں اب کم ہی ہتھیار آزمائے جارہے تھے۔ پہلے کی بہ نسبت اس اکلوتی سڑک پر اب مزید لوگ چہرے پر مسکراہٹیں لیے دکھائی دیے۔ جہاں پہلے کھیتی باڑی ہوتی دکھائی دی تھی، وہاں اب تنہائی اور مال مویشی زمین کی نگرانی کر رہے تھے۔
میری نظر ان پیلے رنگ کے پھولوں پر پڑی جو نزدیک سے گذرتے ہر راہگیر کا خیر مقدم کرتے محسوس ہو رہے تھے۔ یہ کوئی حادثاتی باغیچہ تھا۔ ابھی وہاں سے گزر ہی رہے تھے کہ اس حادثاتی باغیچے کی مالک دو تتلیاں پھولوں کی نگہبانی کے لیے منڈلاتی نظر آئیں۔ میری نظر میں اس دن کا سب سے تعجب انگیز واقعہ یہی تھا کہ ایک ایسی جگہ جہاں زمین کی کوکھ میں اتنے بیج نہیں بوئے جاتے تھے جتنا لوہا گاڑا جاتا تھا، وہاں بھی قدرت اپنی بقا کو یقینی بنائے ہوئے ہے!
 لکھاری انگلش لٹریچر گریجویٹ اور پارٹ ٹائم جرنلسٹ ہیں جو ایسی چیزوں کے بارے میں لکھتے ہیں جنہیں عام طور پر توجّہ کے قابل نہیں سمجھا جاتا. ان کا تعلق سندھ سے اور رہائش اسلام آباد میں ہے جہاں وہ ایک این جی او کے ساتھ بطور 'کمیونیکیشنز ایکسپرٹ' کام کرتے ہیں.
لکھاری انگلش لٹریچر گریجویٹ اور پارٹ ٹائم جرنلسٹ ہیں جو ایسی چیزوں کے بارے میں لکھتے ہیں جنہیں عام طور پر توجّہ کے قابل نہیں سمجھا جاتا. ان کا تعلق سندھ سے اور رہائش اسلام آباد میں ہے جہاں وہ ایک این جی او کے ساتھ بطور 'کمیونیکیشنز ایکسپرٹ' کام کرتے ہیں.













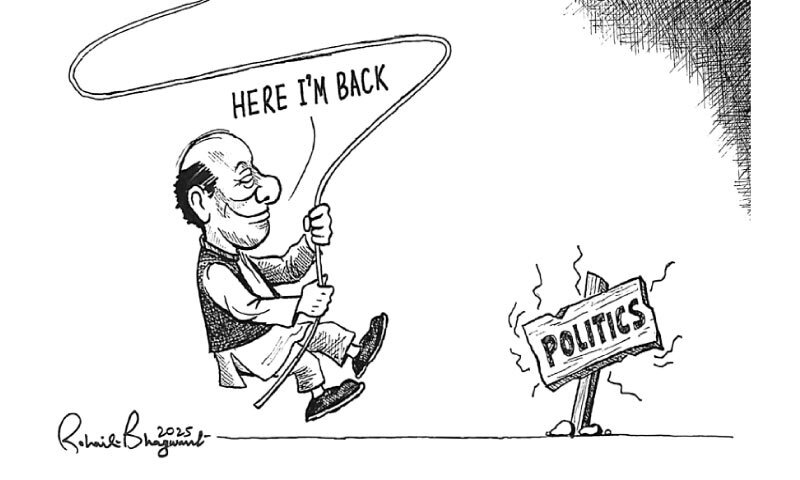





 لائیو ٹی وی
لائیو ٹی وی
تبصرے (4) بند ہیں