افغانستان میں گزرے دن، جب موت کے منہ سے واپسی ہوئی
جیسے جیسے امریکی انتخابات قریب آتے جارہے ہیں، ویسے ویسے وہاں سے نئی خبریں اور نئے دعوے سامنے آرہے ہیں۔ انہی خبروں میں سے اہم ترین خبر اس وقت سامنے آئی جب گزشتہ ہفتے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ٹوئٹ کے ذریعے یہ کہا کہ افغانستان میں موجود تمام امریکی فوجی کرسمس تک اپنے گھروں پر ہونے چاہئیں۔ اس ٹوئٹ کے جواب میں طالبان کا مؤقف بھی سامنے آیا اور انہوں نے ٹرمپ کے اس بیان کا خیر مقدم کیا۔
اس بیان کے بعد مجھے اسی ماہ کے شروع میں لاہور سے آئے دوست سے ملاقات یاد آگئی۔ یہ اکتوبر کے اوائل کا ایک ڈھلتا ہوا دن تھا۔ سڑک پر معمول کے مطابق ٹریفک جام تھا۔ ہوٹل میریٹ کراچی کی پارکنگ کورونا لاک ڈاؤن کے بعد سے اب تک خالی خالی تھی۔ ہوٹل میں کوئی تقریب تھی اس لیے لابی میں خوش گپیاں کرتی خواتین نظر آرہی تھیں۔ ایسا محسوس ہورہا تھا جیسے ہوٹل کے کمرے بھی شاید پارکنگ کی طرح خالی ہی تھے کیونکہ راہداریوں میں عجب سا سکوت طاری تھا۔
ہمارے دوست ڈاکٹر فیصل ہاشمی معروف ملٹی نیشنل ادارے میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں۔ گفتگو کا آغاز تو حال احوال سے ہی ہوا لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ آج کی ملاقات میں ڈاکٹر فیصل کی زندگی کے بڑے حادثے کا تذکرہ بھی ہوگا جو ذہن پر ان منٹ نقوش چھوڑ دے گا۔
ہوا کچھ یوں کہ اچانک میں نے پوچھا، ’ڈاکٹر صاحب آپ اپنے ادارے کے لیے پاکستان اور افغانستان ریجن دیکھتے ہیں، تو آپ کا افغانستان کا تجربہ کیسا تھا؟ کچھ ہمیں بھی بتائیں‘۔
یہ سوال نہیں گویا جیسے کوئی بم ہو جس کی تباہی کے بعد گہری خاموشی پھیل گئی۔ ڈاکٹر فیصل ہاشمی کا چہرہ سوال کے بعد اچانک زرد پڑگیا اور پیشانی پر پسینہ ہوٹل کے کمرے کی مدہم روشنی میں شبنم کے قطروں کی مانند چمکنے لگا۔ خاموشی کے طویل پڑتے وقفے کو ڈاکٹر صاحب کی گھمبیر آواز نے کچھ یوں توڑا۔
’بھائی اپنی دوسری زندگی پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ وہ دن آج تک نہیں بھولتا۔ اب بھی گولیوں کی آوازیں اور زخمیوں کی سسکیاں کانوں میں گونجتی ہیں۔ اکثر سکون کو اضطراب کی گہرائی میں دھکیل کر تماشا دیکھتی ہے‘۔
کچھ خاموشی کے بعد ہمت کرکے دوبارہ پوچھا، ڈاکٹر صاحب آخر ہوا کیا تھا؟ آگے کی داستان ڈاکٹر صاحب کی زبانی کچھ یوں تھی۔
’کمپنی کے کام سے اکثر افغانستان بھی جانا ہوتا تھا۔ کابل بھی اسلام آباد جیسا ہے، پہاڑوں میں گھرے پیالے کی مانند، بس فرق اتنا ہے کہ پہاڑوں پر سبزہ نہیں بلکے بے ترتیب گھر ہیں۔ سڑکوں پر ٹیکسی گاڑیوں کی بھرمار ہے اور اندرون شہر کی گلیاں بے ترتیب اور کراچی کے لیاری کی طرح تنگ ہیں۔ کابل کا سرینا ہوٹل افغانستان کے ایوانِ صدر اور سرکاری دفاتر سے بمشکل آدھا کلومیٹر دُور ہے۔ یہاں متعدد ناکام حملے ہوچکے ہیں۔ یہ علاقہ کسی فوجی چھاونی کی مانند ہائی سیکیورٹی زون ہے۔ ہوٹل میں زیادہ تعداد غیر ملکیوں کی ہوتی ہے جبکہ متمول افغان بھی خاص طور پر ریسٹورنٹ اور لابی میں دکھائی دیتے تھے۔
’وہ مارچ 2014ء کی ایک شام تھی۔ کابل کا موسم قدرے سرد تھا۔ سرینا ہوٹل میں بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی تھی جو افغان الیکشن آبزور کی حیثیت سے مصروف تھے۔ صدارتی انتخابات بس ہونے ہی والے تھے اور مہمانوں میں مقامی اور غیر ملکی صحافیوں کی بھی مناسب تعداد موجود تھی۔ ریسٹورنٹ میں جشنِ نوروز منانے کے لیے بھی کافی مہمان مدعو تھے۔ رات 9 بجے کے قریب میں بھی اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ دن بھر کے کام کا جائزہ اور اگلے روز کی پلاننگ کے لیے موجود تھا۔ کھانے سے قبل ابھی سوپ کا آرڈر ہی دیا تھا۔ ہر ٹیبل پر مدہم سرگوشیاں ہو رہی تھیں، چہروں پر اطمینان تھا اور ہم 3 کولیگ کونے کی ایک ٹیبل پر قبضہ جمائے بیٹھے ماحول اور گرما گرم سوپ سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔
’میرے ساتھیوں میں ایک 27 سال کا دبلا پتلا جوان سلیم تھا اور پہلی مرتبہ ہمارے ساتھ افغانستان آیا تھا جبکہ دوسرا ساتھی کمپنی کا سینئر اور تجربے کار عہدیدار تھا۔ کون جانتا تھا کہ اچانک سب بدلنے والا ہے کیونکہ یکدم چھوٹے ہتھیار کی مسلسل فائرنگ نے پُرسکون ماحول کو تاراج کردیا۔ ہولی وڈ کے فلمی منظر کی مانند لوگوں نے اپنے سامنے ٹیبل کو الٹا کرنا شروع کردیا۔ فائرنگ سے بچنے کے لیے جب زمین پر گرنے لگا تو چمچ اور پلیٹیں اڑنے کا منظر آخری عکس تھا۔ اگلا منظر مزید دردناک تھا کیونکہ میرے ایک ساتھی کے سر میں 2 گولیاں پیوست ہوچکی تھیں جبکہ دوسرا جوان تو شاید ٹراما میں ہی چلا گیا تھا۔ وہ برف کی مانند کرسی پر ہی جم گیا تھا۔
’میرا دماغ ماؤف ہوچکا تھا۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جیسے چھین لی گئی ہو۔ زبان پر یااللہ خیر کے الفاظ ریکارڈر کی مانند جاری تھے۔ پہلا خیال یہی تھا کہ شاید ریسٹورنٹ میں موجود کوئی 2 مقامی گروپ آپس میں لڑ پڑے ہیں لیکن اچانک گونجتے نعروں نے بتادیا کہ یہ آپس کی کوئی لڑائی نہیں بلکہ حملہ ہے۔ صوفے کے پیچھے چھپ کر یااللہ خیر کا ورد کر رہا تھا اور سامنے میرا ساتھی بے دم اور خون میں لت پت پڑا تھا۔ اچانک قریب آتے قدموں کی چاپ نے کپکپاہٹ کو مزید تیز کردیا۔ ایسا لگا جیسے کوئی کمزور شجر تیز آندھی میں تنہا کھڑا ہو۔ حملہ آور نے اپنا پستول میرے گلے پر لگا دیا۔ میں بولنے کی کوشش کرتا رہا لیکن زبان نے ساتھ دینے سے انکار کیا اور ٹوٹے پھوٹے الفاظ بس یہی تھے کہ ہم مہمان ہیں ہمیں چھوڑ دو، لیکن حملہ آور جیسے احساس سے عاری ہو۔ اس نے گردن پر رکھی پستول سے فائر کردیا۔ یوں محسوس ہوا جیسے گرم سلاخ کسی نے آر پار کردی ہو۔ چند سیکنڈ میں ہی احساس ہوا کہ گولی نہیں چل سکی۔ آنکھیں کھولیں تو 20، 22 سالہ جوان حملہ آور اپنی پستول میں گولیاں بھرنے کی کوشش کر رہا تھا بس وہی لمحہ تھا جب زندگی کی پکار نے ذہن کو فوری بھاگنے کا حکم دیا۔
’اپنے نوجوان ساتھی کو آواز لگائی کے بھاگ چلو۔ وہ بھی شاید اسی لمحے کے انتظار میں ساکت بیٹھا تھا۔ ہمارے پاس بس میگزین کے لوڈ ہونے تک کا ہی وقت تھا کیونکہ حملہ آور دہشت گرد کسی رحم کے موڈ میں نہیں تھا۔ ہم دونوں کی زندگی کی جیسے میراتھن ریس کی فنش لائن کراس کرنے کی جدوجہد ہو۔ ہم کچن کی جانب بھاگ نکلے اور قدم تھے کے جیسے بے جان ہونے کے باوجود آخری جدوجہد کے لیے تیار تھے۔ میں کچن کے دروازے کو کراس کرتا سامنے دیوار سے ٹکرایا جبکہ میرا ساتھی کچن کے ایک اور اندرونی دروازے کو بند کرکے اپنے آپ کو محفوظ کرچکا تھا۔ میں دیوار سے ٹکرا کر اپنی بائیں جانب بھاگا۔ یہ ہوٹل کے کمروں کی راہداری تھی۔ میری مدد مدد کی للکار کو سن کے کمروں کے دروازے کھلنے کے بجائے ایک ترتیب اور تیزی سے بند ہوتے گئے۔ ہوٹل کے مکینوں نے مجھے پناہ دینے سے انکار ہی کردیا تھا۔ چونکہ میرے پروفیشنل کیریئر کے ابتدائی 5 برس پاکستان کے ایک بڑے ہوٹل میں کام کرتے گزرے تھے، اس لیے مجھے معلوم تھا کہ ہوٹل کے کمروں کا ایمرجنسی دروازہ کس جانب ہوتا ہے۔ میرے ڈگمگاتے قدم اسی جانب تھے اور فائرنگ کی آواز اب بھی آرہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی موت کا پروانہ لیے اب بھی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ ایمرجنسی گیٹ کو بار بار دھکا دیا لیکن لاک نہیں کھل رہا تھا۔ موت کا خوف پوری طاقت سے میرے وجود سے ٹکرا رہا تھا۔ ایسے میں اچانک نظر پڑی کے سیاہ دروازے کے اوپر کسی نے سیاہ کنڈی لگائی ہوئی ہے۔ بس کنڈی کھولی تو باہر سے آتی ٹھنڈی ہوا نے ایک دم زندگی کا پیغام دیا، لیکن کشمکش یہ تھی کے ایمرجنسی سیڑھی سے اگر اتر بھی گیا اور دروازے کی دوسری جانب بھی دہشت گرد ٹولا موجود ہوا تو کیا ہوگا؟
’اچانک قالین کے نیچے نرمی کا احساس دلانے کے لیے استعمال ہونے والی شیٹ کے بڑے بڑے رول دکھائی دیے۔ بس اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے چھلانگ لگادی اور رول کے اندر اپنے آپ کو سمیٹ لیا۔ خواہش یہی تھی کہ اب یہاں سے کہیں نہیں جانا لیکن اچانک آسمان نے برسنا شروع کردیا۔ پانی کے قطرے جسم کو منجمد کرنے لگے تھے اور سوچا کہ اگر ایسے ہی مزید وقت گزارا تو گولی سے تو شاید بچ جاؤں مگر ٹھنڈ سے موت واقع ہوجائے گی۔ احساس ہوا کہ ساری رات اس حال میں نہیں گزر سکتی، اور تکلیف نے فیصلہ کروا دیا کہ اب یہاں سے نکلنا ہے چاہے پھر گولی ہی کیوں نہ زندگی چھین لے۔ ہمت مجتمع اور باہر نکلا تو دیکھا کہ راہداری کی جانب وقفے وقفے سے لوگ بھاگتے دکھائی دے رہے تھے۔ لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ خیر خواہ ہیں یا دشمن؟ لیکن میں نے فیصلہ کرلیا تھا کہ سردی سے جم کر نہیں مرنا۔ حلق خشک اور آواز جیسے روٹھی ہوئی تھی اور بار بار آواز دینے کی کوشش کرنے کے باوجود کامیابی نہیں مل رہی تھی، لیکن مسلسل محنت کے بعد بالآخر آواز نے وفا کی اور بھاگتا ہوا شخص ایک دم ٹھٹھک کر رک گیا۔ لیکن وہ چند لمحے رکنے کے بعد پھر بھاگتا ہوا کچھ دُور چلا گیا اور دُور سے آواز لگائی کون ہو؟ اسے جواب تو نہیں دے سکا بس ہاتھ کھڑے کردیے۔ میرا انتظار چند ہی لمحوں کا تھا کیونکہ سپاہیوں کا ایک دستہ پوزیشن لیتے ہوئے مجھے کور چکا تھا۔ میرے ہاتھ فضا میں بلند تھے قدم بس جسم کا بوجھ گرانے ہی والے تھے کہ اسپیکر پر کرخت فوجی آواز نے پوچھا کون ہو تم؟ بتانے کی کوشش کی مہمان ہوں ہوٹل میں ہی مقیم ہوں۔ ہاتھ اوپر اور لڑھکتا جسم دیکھ کر فوجی قریب آچکے تھے۔ سہارا دیا تو بس پھر جسم نے مزید ساتھ دینے سے انکار کردیا اور آنے والوں کے آسرے میں نڈھال جسم ان کے حوالے کردیا۔
’لیکن یکایک میرے ذہن میں اپنے ساتھی سلیم احمد (فرضی نام لیکن حقیقی کردار)کا خیال آیا جس کے سر میں میری آنکھوں کے سامنے کم از کم 2 گولیاں پیوست ہوئی تھیں۔ میرے نڈھال جسم میں جیسے برق کوندی ہو اور میں فوری ریسٹورنٹ کی جانب بھاگا۔ وہاں تو جیسے قیامت کا منظر تھا، ہر جانب زخمی اور لاشیں تھی۔ فوجی جوان ابتدائی طبّی امداد اور زخمیوں کی منتقلی میں مصروف تھے۔ وہاں اے ایف پی کے لیےکام کرنے والے مشہور افغان صحافی سردار خان اپنے 2 بچوں اور اہلیہ کے ہمراہ جان کی بازی ہار چکے تھے۔ بہت سے اور غیر ملکی اور مقامی افغان بھی موت کی وادیوں میں جاچکے تھے۔
’میں دیوانہ وار سلیم کو ڈھونڈے لگا لب پر یااللہ رحم کا کلمہ رواں تھا۔ معلوم ہوا کہ سلیم کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ اپنی کمپنی کے ہیڈ آفس رابطہ قائم کرکے انہیں صورتحال سے آگاہ کیا اور کمپنی فوری طور پر متحرک ہوگئی۔ سلیم کو ایئر لفٹ کروا کر دبئی منتقل کرنے کی تیاری شروع ہوچکی تھی۔ اپنی زندگی میں بار بار دبئی جانے کا خواہش مند میرا ساتھی کس حال میں دبئی جا رہا تھا یہ سوچ کر ہی دل شدید مغموم تھا۔ سلیم کو دبئی کے اعلیٰ ترین اسپتال میں منتقل کیا گیا۔ گولی دماغ کو چُھوتے ہوئے پیشانی کے قریب پھنسی ہوئی تھی، جو آپریشن کے ذریعے نکال دی گئی جبکہ دوسری گولی ڈاکٹرز نے فی الحال نہ نکالنے کا فیصلہ کیا۔ سلیم 3 ماہ تک مکمل کومے میں رہا۔ اس دوران دماغی بخار کی وجہ سے اس کی پیشانی کو بائیں جانب سے کٹ لگا کر دماغ کو کھلا رکھا گیا۔ پھر 3 ماہ بعد ڈاکٹرز نے فولادی پلیٹ لگا کر اسے بند کردیا اور اللہ کے حکم سے 3 ماہ بعد سلیم کو ہوش آگیا۔ آہستہ آہستہ سلیم کے حواس بحال ہونے لگے، یادداشت واپس آنے لگی لیکن جسم حرکت سے قاصر تھا۔ ابتدائی طور پر اسے یہی بتایا کہ تم آفس میں گر گئے تھے اور میز کا کونا لگنے کی وجہ سے یہ حال ہوا ہے۔ لیکن پھر ایک روز سلیم نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کہا کے مجھے بلایا جائے۔ اسپتال کے عملے نے بڑی مشکل سے سلیم کی بات سمجھی اور مجھے دبئی اپنے ساتھی سے ملنے جانا پڑا۔ میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور کابل سرینا کا قتلِ عام میری آنکھوں میں گھوم رہا تھا۔ سلیم اب کافی حد تک خطرے سے باہر تھا۔ مجھے بڑی مشکل سے سلیم نے سمجھایا کہ ہم دفتر میں نہیں بلکہ افغانستان میں تھے، وہاں حملہ ہوا اور مجھے گولیاں لگی تھیں۔ انکار ممکن نہ تھا کہ سلیم کو اب سب یاد آچکا تھا۔
اب اس واقعے کو تقریباً 6 سال گزر چکے ہیں۔ سلیم اپنی ویڈیو بناکر بھیجتا ہے جس میں وہ تلاوت کرنے کی اور خود چلنے پھرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس پورے عرصے کے دوران کمپنی نے ہمارا بہت ساتھ دیا۔ سلیم آج بھی ناصرف کمپنی کا ملازم ہے بلکہ تمام سہولیات بھی فراہم کی جارہی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ کمپنی اب یہ نہیں چاہتی کہ میں کبھی افغانستان جاؤں۔ 6 سال بعد بھی کابل سرینا ہوٹل کا قتلِ عام کسی فلم کی مانند پردہ دماغ پر جب بھی چلتا ہے تو رونگھٹے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے ایک اور زندگی دی۔
اکتوبر کا مہینہ افغانستان کے لیے اہم رہا ہے۔ گوکہ عام طور پر 8 اکتوبر 2001ء کو افغانستان پر امریکی حملے کو نائن الیون کے دہشت گرد حملوں کا ردِعمل قرار دیا جاتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی ابتدا 15 اکتوبر 1999 کو اس وقت ہوئی تھی جب اقوامِ متحدہ نے القاعدہ اور افغان طالبان پر پابندیوں کا آغاز کیا تھا۔ اب اکتوبر 2020ء میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے افغانستان سے کرسمس تک فوج کے انخلا کا اعادہ کیا ہے۔ جنگ تو اب ختم ہو ہی جائے گی لیکن اپنے پیچھے نہ جانے کتنے ڈاکٹر فیصل اور سلیم جیسے لوگوں کی زندگیوں پر ان مٹ نقوش چھوڑ جائے گی کیونکہ ہر جنگ کے پیچھے ایسی ہی دلخراش داستانیں ہزاروں خاندانوں کی زندگی کا تکلیف دہ باب بن جاتی ہیں۔








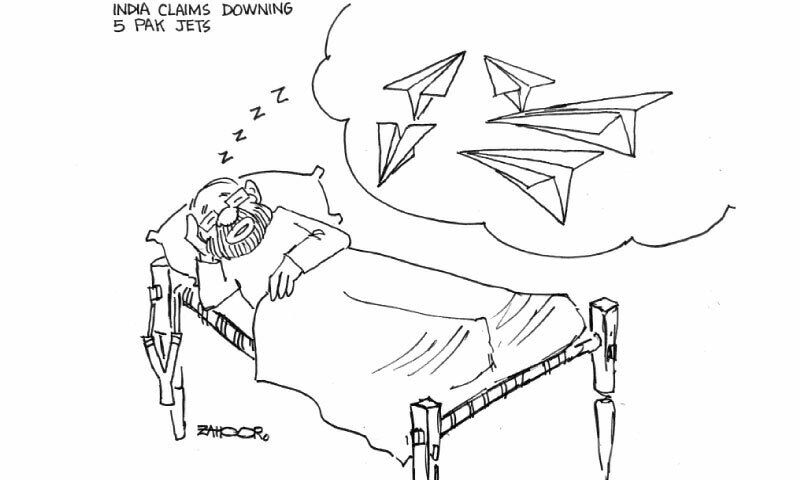





 لائیو ٹی وی
لائیو ٹی وی
تبصرے (1) بند ہیں